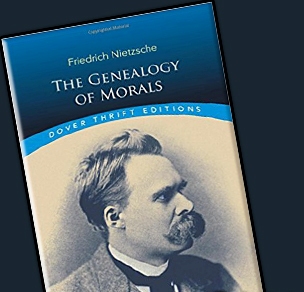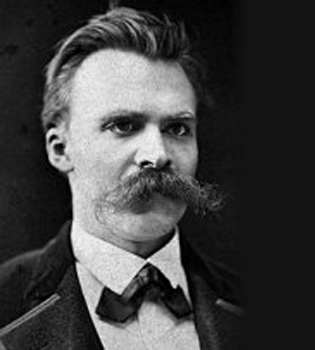بے مقصدیت، یا اسکو لامقصدیت کہنا چاہئے؟نفسیات کی زبان میں کہیں تو میجر ڈپریشن؟
صورت حال یوں، کہ زندگی کے اندر سے سارے رنگ جیسے گُم ہوگئے۔ سب منظر پھیکے، ساری باتیں بے کیف، ہر کیفیت بے سُرور۔
پژمردگی، مردنی، ایک مہیب وجودی لایعنیت۔
مشکل یہ ہے کہ ایسی کیفیت ہر آدمی پر طاری ہوتی ہے۔ کسی پر زیادہ شدت کیساتھ ہوتی ہے، کسی پر کم۔ کسی کیلئے اس کیفیت کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، کسی کیلئے طویل، کسی کیلئے طویل تر اور کسی کیلئے مستقل۔ارادہ یہ ہے کہ اس کیفیت کی جو فلسفیانہ قسم ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے۔ اور آخر میں اس کی کچھ تنقید بھی کرنے کی کوشش ہو۔
فلسفیانہ اداسی ظاہر ہے کہ فلسفیوں پر ہی طاری ہوتی ہے۔مشاھدہ یہ بھی ہے کہ اس قسم کی اداسی میں فلسفیانہ گہرائی اور فکری شکوہ پیدا کرنے کیلئے اسے ‘وجودی بحران’ اور ‘وجودی لایعنیت کا احساس’ وغیرہ کے بھاری بھرکم ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں کہیں اگر، تو وزن دو چار کلو مزید بڑھ جاتا ہے؛ ایگزیسٹینشل کرائسس! ان اصطلاحی ناموں کی ایک پوشیدہ حکمت یہ ہے کہ حاملِ اداسی فلسفی اس لایعنیت کے اندر سے بھی اصطلاح کے زور پر خود ستائی اور اپنی اہمیت کا کچھ عرق کشید کرسکے۔ اور یوں اپنی اداسی کو غیر فلسفیانہ اداسی سے ممتاز دکھا سکے۔
آپ سوچتے ہونگے کہ یہ تنقید تو تذکرے سے پہلے ہی شروع ہوگئی ہے۔ اسلئے فی الحال فلاسفہ کی اتنی سرزنش کو کافی جانتے ہوئے فلسفیانہ اداسی یا لایعنیت کی پیدائش و پرداخت کے اسباب کا کچھ تجزیہ کرلیتے ہیں۔
ڈپریشن کے حوالے سے طبّی نفسیات کا ایک موٹا اصول یہ ہے(سارے اصول موٹے ہی ہوتے ہیں) کہ شدید اداسی اور ڈپریشن میں مبتلا شخص بھی اگر بے رنگی اور بے کیفی کے عذاب کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے جب تک اپنی بنیادی زمہ داریاں ادا کرتا رہے، بیمار شمار نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک اپنی صحت کا خیال رکھتا رہے، جن افراد کی دیکھ بھال اسکے ذمے ہے انکا خیال رکھتا رہے، طبّی نقطہ نظر سے تب تک اس شخص کو ایسا ڈپریشن نہیں ہے کہ جہاں علاج ضروری ہوجائے۔ تاآنکہ اُس سے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے متواتر یا مستقل کوتاہی سرزد ہونی شروع ہوجائے۔ مثلاً صبح بستر سے اٹھ ہی نہ پائے۔ کام پر نہ جاسکے۔ کھانا پینا چھوڑ دے۔ وغیرہ۔ اگر اس طرح کی صورت حال کا سامنا ہو، یعنی مذکور شخص اپنی بنیادی انسانی بلکہ حیوانی ذمہ داریاں بھی نہ پوری کرسکے، تو پھر ایسے شخص کو نفسیاتی مریض قرار دے کر اس کا علاج دواؤں اور دیگر طریقہ ہائے گوناگوں سے کیا جاتا ہے جو طبّی نفسیات میں رائج ہیں۔
حیوان کی بات آگئی تو یہاں تحریر میں وزن پیدا کرنے کیلئے حیوانات کا بھی کچھ ذکر شامل کرلیتے ہیں۔
جدید سائنسی مزاج کی ایک مصیبت یہ ہے کہ فوراً جانوروں کیساتھ تقابل کرنے کو دوڑتا ہے۔ مابعد ڈارون عہد میں پیدا ہونے کی زمانی نحوست میں چونکہ مصنف بھی جبراً مبتلا ہے اسلئے یہ سوال سرسری طور پر پوچھ کر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجودی اداسی کی یہ کیفیت جانوروں پر بھی طاری ہوتی ہوگی؟
مگر سرسری طور پر آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔
اس سوال کا جواب دینے کے ارادے کیساتھ پہلے ہی قدم پر چند مزید سوال فوری پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس بات کو طے کرنے کا کیا طریقہ ہوگا آخر،کہ جانور بھی اس کیفیت سے گذرتے ہیں؟ یا نہیں۔ کونسا “سائنسی تجربہ” یہ بتا سکے گا کہ واقعی جانوروں پر بھی ڈیپریشن طاری ہوتا ہے۔ اس مذکورہ تجربے کے درست ہونے کا معیار کیا ہوگا۔ دوسری طرف اس تجربے کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کے کیا اصول ہونگے۔ وہ اصول کس نے متعین کئے۔ ان اصولوں کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ اُن اصولوں کی حیثیت متعین کرنے میں بھی کچھ اصول ہی کارفرما رہے ہونگے۔ یا بس یونہی؟
اور پھر جانور ہی کیا۔ انسانوں کے اندر کی اداسی کو بیماری یا ڈپریشن قرار دینے کا جو موٹا اصول اوپر بیان ہوا ہے، اس پر بھی تو اسی نوعیت کے سوال اٹھائے جاسکتے ہیں۔ کہ یہ کوئی اصول تو نہیں، ایک طرح کی سودے بازی اور کمپرومائز ہی ہے۔ آخر کب ہم کہیں گے کہ یہ آدمی اپنی زمہ داریاں پوری کررہا ہے اور وہ عورت نہیں کررہی۔ ایسے معیار طے کرنے کا اختیار ہمیں کس نے دیا ہے۔ ہفتے میں کتنے دن کام پر نہ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص اب بیمار ہے۔ اور کام پر نہ جانے کی وجہ میں سے خالص عدم دلچسپی اور وجودی لایعنیت کے علاوہ باقی ممکنہ عناصر کو الگ کیسے کرینگے اور کس کے کہنے پر اور کیوں کرینگے؟
اور پھر یہ کہ جو شخص اپنے اندر مکمل سرایت کی ہوئی ایسی لایعنیت اور بے مقصدیت کے باوجود گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے، اسکا کیا قصور ہے کہ اسکو معذور سمجھ کر رخصت نہیں دی جاتی۔ اور جو ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، اسکے علاج کیلئے دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔؟
جو موٹا اصول ان تفصیلی سوالات کا سامنا کرنے سے گھبرا کر فوری ضرورت کے تقاضے کے تحت بنالیا گیا ہےـ اسکی حیثیت تو بس ایک عارضی بندوبست کی سی ہے۔
المیہ یہ ہے کہ ایسا بندوبستی بودا پن صرف اس طبّی نفسیاتی اصول تک محدود نہیں ہے۔ جس بھی کارآمد عملی اصول کو اس طرح پرکھا جائے گا، چاہے اسکا تعلق کسی شعبے سے ہو۔ اسکی نوعیت اسی طرح کی برآمد ہوگی۔ عارضی، مصلحتاً ترتیب دیا گیا، بندوبستی۔
فلسفیانہ اداسی چنانچہ ایک طرف، اسی نوعیت کے ختم نہ ہونے والے سوالات کے تسلسل سے، اور دوسری طرف ادھورے اور ناکافی جوابات پر اکتفا کرکے بندوبستی اصول قائم کرلینے، اور پھر ان پر عمل پیرا ہوجانے کے بعد مزید سوالوں سے نظریں چرانے والے رویّوں کے بودے پن کے خلاف ایک ردّ عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔
ان اصولوں کا بودا پن جن لوگوں پر واضح ہے اور کچھ کر نہیں پاتے، وہی فلسفیانہ طور پر اداس ہیں۔ یہ فلسفیانہ اداسی ہے۔ اور یہی وجودی لایعنیت ہے۔
کچھ کر اسلئے نہیں پاتے کہ کچھ کرنا چاہتے نہیں۔ ایسے فلسفیانہ مزاج افراد کی وجودی لایعنیت انہیں کچھ نہ کرنے پر قائل کئے رکھتی ہے۔ انکے نزدیک اہداف متعین کر کے، اور اصول طے کرکے کام کرنے والے لوگ درمیانے اور پست درجے کی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں، اور غور نہیں کرتے۔ انکا کہنا ہے کہ کام اگر کوئی کیا بھی جائے تو اسکے پیچھے مقصد کوئی نہیں ہونا چاہئے۔ بس یونہی کرلیا جائے۔ “بس یونہی” اور “مقصد” انکے نزدیک برابر ہیں۔ کیونکہ زندگی کے تمام اصول “بس یونہی” بنے ہیں اور انکی کوئی مستقل بنیاد نہیں ہے، اسلئے مستقل اصول ایک فریب ہے اور اس اصول کی موجودگی کے دعویدار سب فریبی۔
یہ نقطہ نظر ایک ایسے وجودی خلا کو جنم دیتا ہے جو وقت گذرنے کیساتھ مستقل لایعنیت کے احساس میں ڈھل جاتا ہے۔ اور پھر صورت حال یوں ہو جاتی ہے، کہ زندگی کے اندر سے سارے رنگ جیسے گُم ہوگئے۔ سب منظر پھیکے، ساری باتیں بے کیف، ہر کیفیت بے سُرور۔
پژمردگی، مردنی، ایک مہیب وجودی لایعنیت۔۔۔۔
اس کیفیت کی شدت سے جان چھڑانے کیلئے آدمی نشہ کا استعمال شروع کرسکتا ہے اور انتہائی صورتوں میں خود کُشی تک بھی نوبت آسکتی ہے۔
جدید فلسفی کیلئے آج یہ ایک بڑا زندہ چیلنج ہے کہ ایسی، اپنے ہاتھوں محنت اور غور و فکر کرکےکمائی ہوئی لایعنیت کے فلسفیانہ نتیجے کیساتھ زندگی کے تقاضوں کا جوڑ کیسے لگائے۔ وہ تقاضے جو زندہ دلی اور دلچسپی کے بغیر پورے نہیں کئے جاسکتے۔ ان تقاضوں کا تعلق زندگی گذارنے کے بہت بنیادی اور اہم ترین معاملات کیساتھ ہے جنکے بغیر زندگی مفلوج ہوجاتی ہے۔ جیسے روزی کمانے کی غرض سے کوئی ملازمت/کاروبار کرنا۔ کھانا کھانا۔ وقت پر سونا، وقت پر جاگنا۔ بیوی/خاوند بچوں کی زمہ داریاں پوری کرنا۔ قوانین کی پاسداری کرنا۔ والدین کے حقوق ادا کرنا وغیرہ۔
وجودیاتی فلاسفہ کی تحاریر میں جا بجا اس لایعنیت کے مظاہر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر البرٹ کامیو کے مشہور ناول “دی سٹرینجر” کا اس بامسمّٰی مرکزی کردار ‘مرسوو’ جو اپنی والدہ کے جنازے پر بھی جذبات سے عاری رہتا ہے، اس شام بھی عیاشی میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ پھر کسی کو قتل کرکے جیل جاتا ہے اور موت کی سزا کا اسی عدم جذبات کیساتھ انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ موت کی سزا پر عمل درآمد ہوجاتا ہے۔
یا پھر دوستیوسکی کا “نوٹس فرام انڈرگراؤنڈ” جہاں لایعنیت کے دیگر بیانات کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے، کہ بے عملی ہی اعلی ذہانت کا اولین مظہر ہے۔ اگرچہ اپنے اس نتیجے سے بھی وہ خوش اور مطمئن نہیں ہوتا۔
ہمارے ہاں جون ایلیا کے کلام میں اس طرح کی وجودی لایعنیت کے زوردار اشارے ملتے ہیں۔ اپنے احباب کی مصنوعی اور خود ساختہ فلسفیانہ بے عملی پر انکا ایک طنزیہ شعر یوں ہے کہ
یہ خراباتیانِ خِرَد باختہ
صبح ہوتے ہی سب کام پر جائینگے!
صبح ہوتے ہی کام پر جانے کو خردباختگی کہنے والے اس انوکھے شاعر نے خود ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا اور اسی طرح اپنی زندگی تباہ کرلی۔ مگر دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہ
میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
وجودی لایعنیت کا یہ رویہ جدید فلسفہ کا (ادبیات کا بھی) ایک غالب ذہنی رویہ ہے۔ ہماری طالب علمانہ نظر میں جون صاحب کی جدید مقبولیت کے شدت سے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیچھے اِس جدید فلسفیانہ رویے کا بھی ہاتھ ہے جو ہمارے ہاں کا جدید آدمی دانستہ یا نادانستہ اپنے اندر جذب کرچکا ہے۔ اسی یاسیت زدہ رویے سے ابسرڈزم اور مابعد جدید کے بے سروپا لسانیاتی فلسفے پھوٹے ہیں اور پھوٹتے جارہے ہیں۔ (مابعد جدید فلسفہ اور فلاسفہ کو بے سروپا کہنے سے انکو یقیناً خوشی ہوتی ہے)۔ اس رویے کی فلسفیانہ تنقید فلاسفہ کی طرف سے ہونی چاہئے۔
مضمون کے شروع میں تفصیلی تنقید کا وعدہ مصنف کی طرف سے بھی کیا گیا تھا مگر طوالت کے خوف کے پیش نظر تنقیدی حصّے کو الگ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔
ضروری فرہنگ:
۱۔ وجودی بحران: existential crisis
۲۔ وجودیاتی فلاسفہ:existential philosophers
یقین کی فلسفیانہ بنیاد:
یہ بیان تو کسی حد تک تفصیل سے ہو چکا کہ فلسفیانہ ذہن میں وجودی لا یعنیت کی کیفیت اداسی کی ایک ایسی شدید شکل ہے جو اپنے پھیلاؤ میں مکمل اور نفوذ میں گہرا ہے۔ ایسی شدید اداسی کا شکار اگرچہ عام افراد بھی ہوسکتے ہیں، تاہم عام لوگ اس بے معنویت اور لایعنیت تک کسی فلسفیانہ سوال و جواب کے نتیجے میں نہیں پہنچتے۔ ہوتا یوں ہے کہ یا تو انکو کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوگیا یا ایسا ذاتی دکھ پہنچا جو انکی قوت برداشت سے زیادہ تھاـ کوئی ایسی امید تھی جو بر نہ آئی، کوئی مان تھا جو ٹوٹ گیا۔ کوئی خواھش ایسی تھی جو پوری نہ ہوسکی یا کوئی خواب تھا جو بکھر گیا۔ اس طرح کی ذاتی اور سماجی نوعیت کی کسی کاری ضرب نے انکے قویٰ اس قدر مضمحل کردئے کہ نفسیاتی طور پر ایک بیماری کا شکار ہوگئے جسے کہ ڈپریشن کہا جاتا ہے۔
عرض یہ ہے کہ آنے والی بحث کا موضوع ایسے عام افراد نہیں ہیں ـــ باوجود اسکے کہ کیفیتی مماثلت اور کئی دفعہ اس کیفیت کے زیر اثر انتہائی اقدام کے نوعیت کی مماثلت بھی دونوں طرف موجود ہوسکتی ہے، اور ہوتی ہے۔ جیسے نشہ کا استعمال اور خود کُشی فلسفی بھی کرسکتا ہے اور عام آدمی بھی۔
یہاں پر اس حقیقت کو سمجھ کے اور تسلیم کرکے آگے جانا چاہئے کہ ہر درجہ بندی کی طرح یہ تقسیم کاری اور خانہ بندی بھی ایک غیر حقیقی سادگی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ یعنی فلسفی اور عام آدمی کی تقسیم کوئی ایسی صاف ستھری اور واضح تقسیم نہیں ہے۔ فکر ہر انسانی ذہن کا خاصہ ہے۔ اور فکر کی ایسی حد متعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ جس پر کھڑے ہوکر اس سے آگے گذر جانے والے کو فلسفی قرار دیا جائے اور جو اس حد سے پیچھے رہے اسکو عام آدمی کہا جائے۔
یہ حدود اور لائینیں سبھی بیرونی ‘مکانی’ تصورات ہیں اور فکر اندرونی جہان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر خالص ‘زمانی’ ہوتا ہے۔ اس خالص اندرونی زمانی جہان پر بیرون کے مکانی پیمانوں کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔
اس سے پہلے کہ گفتگو زیادہ ثقیل اور فلسفیانہ ہوکر لامکانی ہوجائے، اپنے موضوع کی طرف یہ کہہ کر پلٹ جاتے ہیں کہ ہر طرح کی تقسیم میں کچھ سودے بازی ضرور ہوتی ہے۔ ہم اس کوتاہی اور فکری مجبوری کو تسلیم کرکے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک خاص گروہ یعنی فلاسفہ کے اندر وجودی لایعنیت کا تجزیہ کرنے کی غرض سے کی گئی یہ تقسیم کاری ہماری اپنی اختراع ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس راستے سے اگر کسی کارآمد نتیجے پر پہنچ پائیں تو اُس نتیجے کے دائرہ کار کو عام آدمی تک بھی پھیلایا جا سکے گا۔ فی الحال اس بحث کو پیچیدگی سے بچنے کیلئے صرف فلاسفہ ہی تک محدود رکھیں گے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تقسیم کا یہ اصول بھی اِس بنیاد پر عارضی اور بندوبستی ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو کہنا بھی چاہئے، کہ؛ پچھلی قسط میں آپ بیان کرکے آئے ہیں کہ اِس طرح کے بندوبستی، عارضی اور مصلحتاً ترتیب دئے گئے اصول و ضوابط سے تنگ آکر ہی فلسفیانہ ذہن وجودی لایعنیت کا شکار ہو کر حیات کُش رویوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اور اب آپ مضمون کا آغاز ہی اسی طرح کے ایک بندوبستی اصول سے فرما رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ آپکا یہ اعتراض بالکل درست ہے۔
مگر، یوسفی صاحب کے بقول پھر آپ ہی بتائیں کہ ہم اور کیا لٹکائیں!
یوسفی صاحب تو خدا انکو صحت مند رکھے، اس فقرے کی وجہ سے اور اسطرح کے دیگر انمول فقروں کی وجہ سے اردو ادبیات میں زندہ جاوید ہوگئے ہیں۔
ہم اپنی بے مزہ بات کو آپکی مان کر یہاں سے شروع کرتے ہیں:
اگر آپ کسی بھی نامعلوم وجہ کی بنیاد پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں ــــ کہ ہمارے فلسفیانہ اذہان میں وجودی لایعنیت نام کی ایک بامعنی کیفیت پائی جاتی ہے اور یہ کیفیت جدید آدمی کا ایک غالب رویہ ہے، تو پھر اوپر ہونے والی گفتگو کو بھلا کر اس مشترک زمین سے آگے کا سفر ہم باہم مل کر طے کرلیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟
اور اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو پھر شاید آپکو یہیں سے مڑ جانا چاہئے اور واپس جا کر ممکن ہوا تو پچھلی قسط دوبارہ پڑھ لینی چاہئے۔۔
اتفاق کرنے والوں کی خدمت میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض ہے کہ ہمارا یہ متفق علیہ فلسفیانہ ذہن جو مسلسل سوالات اور ناکافی جوابات کے بودے پن اور پھر انکو تسلیم کرنے کی مجبوری کے باعث ایک وجودی اذیت میں گرفتار ہے، غور فرمائیں تو اس ذہن کے اندر ایسی اذیت کی پیدائش کا ایک مطلب ہے۔
یہ نکتہ توجہ طلب ہے، یہیں کچھ دیر توقف کر کے سوچئیے ــ کہ آخر وہ ذہن اِن جوابات کو ناکافی کیوں کہہ رہا ہے۔ ان بندوبستی اصولوں سے مطمئن کیوں نہیں ہورہا؟ اذیت میں کیوں مبتلا ہے؟ اِس کا ذہن اُن عامیانہ اصولوں کو کس بنیاد پر رد کررہا ہے؟ کس وجہ سے ان کو عارضی اور بندوبستی کہہ رہا ہے؟
اس انکار اور اذیت کی بنیاد یہ ہے کہ اسکے ذہن میں ایک برتر تصور پہلے سے ہی کام کررہا ہے۔ ایک اصول پہلے ہی ذہن کے اندر برسر کار ہے جو اسکو یہ بتاتا ہے کہ یہ جواب ابھی کافی نہیں ہے، ابھی کم ہے، ابھی نامکمل ہے۔ اندر کا یہ اصول اسکیلئے ایک پیمانے اور کسوٹی کا کام دیتا ہے۔ ایک پیمانہ جس پر وہ ہر دوسرے اصول کو پرکھتا ہے، یہ شخص اپنے ذہن کے اندر پہلے ہی پالے ہوئے ہے ـ ممکن ہے اس کی موجودگی کی خود اسے خبر نہ ہو۔
یہ اندرونی اصول مگر اسکے بس سے بالکل باہر ہے۔ یہ اسکی گرفت میں نہیں آتا۔ یہ بس اسکو دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ شاید وہ پیدا ہوا ہے۔ یا شاید وہ اس اصول کے اندر ہی پیدا ہوا ہے۔؟
ذہن کے اندر موجود اِس برتر پیمانے اور سانچے کو جس کی کسوٹی پر ذہن تمام اصولوں کو پرکھتا ہے، اور جنکی مدد سے ذہن دیگر ہر اصول کی تفہیم کرتا ہے، امانویل کانٹ قبل تجربی اصول یا “اے پری یورائی پرنسپلز” کہتا ہے۔ یعنی اس عظیم ترین فلسفی کے مطابق ایسے بنیادی قواعد ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ قبل تجربی اصول جو کسی بھی نوعیت کے تجربے سے پہلے ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، کی بنیاد پر ہی ذہن شے (اصول/ خیال/ تصور سبھی) کیساتھ کسی بھی نوع کی نسبت پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور انہی کی بنیاد پر وہ شے پر کسی قسم کا حکم لگا سکتا ہے۔ فلسفہ سے واقف حضرات یہاں پہنچ کر مصنف کی رجعت پسند قلابازی پر تعجب کرتے ہونگے کہ پچھلی قسط میں جبکہ کسی طور کامیو اور سارتر تک پہنچ گیا تھا، اب پسقدمی کرکے دوبارہ کانٹ کی گود میں جا بیٹھا ہے۔
یہ تعجب بھی بالکل درست ہے ۔
چلیں کانٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی تحریر پر ایک لمحے کیلئے غور کیجئے ــــ اِن الفاظ پر، جو مصنف نے غور و فکر کرکے چن کر لکھے ہیں۔ ان لفظوں کی بناوٹ پر، ان لکیروں پر جن سے یہ لفظ بنے ہیں، انکو ذرا غور سے دیکھیے۔ یہ لکیریں جو دراصل سکرین کی زیادہ روشن سطح پر کم روشنی کے یا اندھیرے دھبے ہیں۔ یہ لکیریں لفظ کیسے بن گئیں؟ یہ دھبّے کس طرح الفاظ بن گئے؟ سوچئے ــ اور پھر انکے اندر معنی کیسے بھر گئے؟۔
کس طرح سکرین کے اندر سے خدا جانے کس کس نوع کے پیچیدہ الیکٹرانکی اور برقی مراحل سے گزر کر ان دھبّوں کے عکس آپکی آنکھ کی پتلیوں سے ہوکر پردے سے ٹکرائے، کیسے اس پردے پر ایک برقی تاثر قائم ہوا، کیسے یہ برقی تاثر برقی رَو بنی اور کس طرح یہ برقی رَو اعصاب پر سوار ہوکر ایک سوراخ کے رستے ذہن میں داخل ہوا۔ وہاں اس رَو پر کیا بیتی کہ وہ لفظ بن گیا؟ واللہ، سوچیے کیا بیتی؟ کیا کچھ نہ بیتی ہوگی اس بے چاری رَو پر کہ پہلے برق سے لفظ بن گئی ـ پھر لفظ سے معنی ہوگیا۔
یہ تمام پیچیدہ ترین سفر جسکو مصنف کی کوتاہ فہمی نے کسی قدر کم پیچیدہ بنادیا ہے، سائینسی حقائق ہیں جن کو ہمارا جدید ذہن چُوں کئے بغیر تسلیم کرتا ہے۔ غور کیجئے کیا کیا الم غلم ہم تسلیم کئے جاتے ہیں، اور بولتے نہیں۔ اس پیچیدہ بیان سے کئی ہزار گنا پیچیدہ اور تہہ دار عمل کو آپ پی پلا کر اس مضمون کے الفاظ کو الفاظ کے طور پر پہچان رہے اور پھر معنی پہنا رہے ہیں۔ یہ سب عمل آپ کیساتھ ابھی ہورہا ہے، اِس وقت۔ اور آپ بغیر سوال کئے اس سب کو مان کرکے بلکہ انہی کی بنیاد پر یہ تحریر سمجھ کر، اسکے معانی کی تائید کررہے ہیں یا ان سے اختلاف کررہے ہیں۔
یہی پیچیدہ حال ہر حس کا ہے۔ دید یا بصارت کا مختصر حال آپ نے پڑھ لیا۔ سماعت اور لمس کی بھی روداد اس سے مختلف نہیں۔ اور یہ ابھی حسّیات کی کہانی ہے۔ جسکے پاس ارتسامات (stimuli) کی شکل میں کچھ خارجی مواد ہے۔ عقلیات کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ خیالی اور اس سے زیادہ ہوائی ہے۔ کہ اسکے پاس برتنے کو کوئی خارجی مواد ہی نہیں۔
اس سب تفصیل کے بعد جدید لایعنی فلسفی سے کہنا یہ تھا کہ کانٹ کا کانٹا اگر نکال بھی دیا جائے، تو مشاھدے ہی سے واضح ہے کہ شعور کی پہلی جست پر ہی ہم آپ سب اس بے بنیاد اور پیچیدہ قواعد کے مجموعے کو درست تسلیم کرکے بلکہ انہی کی بنیاد پر باقی چیزوں کا فہم بہم پہنچاتے ہیں اور ان پر حکم لگاتے ہیں۔ تو پھر جن بندوبستی اصولوں کے بودے پن سے ہماری نازک طبیعت مکدّر ہورہی تھی، کیا وہ اِن پس منظری/ قبل تجربی قواعد کے مجموعے سے زیادہ پیچیدہ ہیں؟ زیادہ بودے ہیں۔ ؟ یہ مجموعہ جو مکان متصور کرتا ہے، پھر اس میں روشنی۔ پھر روشنی کی شدت کے اختلاف کو لکیر بناتا ہے، لکیر کو حرف، حرف کو لفظ اور لفظ کو معنی۔
یعنی یہ اصول اور پیمانے جنکی بنیاد پر آپ اُن عامیانہ اصولوں (عام اصول جیسے آگ سے حرارت اور پانی سے تری کا اثر پیدا ہونا۔ یا پچھلی قسط میں ڈپریشن کی تعریف میں یہ طبی قاعدہ کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرنے لگ جائے۔ یا یہ طبی اصول کہ جراثیم سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دواؤں سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وغیرہ) کی تفہیم کے قابل ہوئے ہیں اور انکو بندوبستی و عارضی کہہ رہے تھے، خود کون سے کوئی حتمی اور ثابت شدہ حقائق ہیں؟
یہ حسیات کے راستے ارتسامات کی پیچیدہ ترسیل اور پھر عقل و فہم کا انکو معانی و مفاہیم میں ڈھالنا جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی شے اور خیال سے کسی بھی درجے میں نسبت پیدا کرتے ہیں، آپ ان کو بھی غلط تسلیم کیوں نہیں کرتے۔؟
انکا بھی انکار کیوں نہیں کرتے؟ ہم بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے۔
آپ ان قبل تجربی اصولوں کا انکار اسلئے نہیں کرتے کہ انکا انکار کر نہیں سکتے۔ انکو اگر آپ نے ناقابل قبول اور غلط قرار دیدیا تو پھر آپکے ہاتھ سے وہ بنیاد ہی چھن جائے گی جس کے بل پر آپ کسی بھی شے/ خیال کو درست یا غلط بتانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب مکان ہی متصور نہ ہوسکے گا تو روشنی کہاں سے آئے گی اور کہاں جائے گی؟ روشنی لفظ ہی نہیں بنے گی اور لفظ معنی ہی نہیں بن سکینگے تو پھر انکار کا کیا مطلب ہوگا اور اقرار کے کیا معنی ہونگے؟
اس نکتے میں ایک خمدار لچک ہے۔ اس پر توقف کریں۔
اس کو کچھ اور کھول کر بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب تک کی کہانی یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ نے اُن عامیانہ اصولوں کو جو روزمرہ برتنے میں آتے ہیں ناکافی اور بے بنیاد سمجھ کر عارضی اور بندوبستی کہہ دیا۔ پھرآپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ ان اصولوں کی جن بنیادوں پر تفہیم کرتے ہیں، وہ بنیادیں بھی تو اصولی ہی ہیں۔ انکو بھی بندوبستی اور بے بنیاد کہیے!
یہ اصول جو حسیات کی ترسیل اور فہم کے مقولات کے نام پر اپنے اندر اُن عام اصولوں سے، کہ جن کو بودا اور عارضی کہہ کر ہم خودکشی کرنے چلے تھے، کہیں بڑھ کر بندوبستیت اور عارضی پن لئے ہوئے ہیں۔ اِنکو بندوبستی اور بے بنیاد کیوں نہیں کہہ دیتے؟
اب یہاں اگر آپ کہیں، کہ نہیں ہم تو ان کو بھی بندوبستی ہی کہتے ہیں۔ ہم انکو بھی نہیں مانتے۔ ہم تو حسیاتی ارستسامات اور عقل کے مقولات، کسی کو نہیں مانتے۔
تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اِن پس منظری قبل تجربی قواعد کو بغیر کسی ثبوت کے درست مانے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ خودکشی کے مطلب بھی نہیں جان سکتے۔ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، کہا ہوا سُن نہیں سکتے۔ آپ نہ کسی شے/خیال کو درست مان سکتے ہیں، نہ غلط۔ بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ ان اصولوں کو درست مانے بغیر کسی بھی شے/ خیال سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی نسبت ہی نہیں پیدا کر سکتے، تعلق ہی نہیں پیدا کیا کرسکتے۔ درست یا نادرست اور غلط یا صحیح کا حکم تو بہت بعد کی بات ہے۔
ان اصولوں کا گھیراؤ اس قدر مکمل ہے، کہ اس سے مفر ناممکن ہے۔ ان اصولوں کا انکار بھی انکا اثبات کئے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ شعور اپنی پہلی حرکت ہی ان اصولوں کو درست مان کر کرتا ہے۔ ان کو درست مانے بغیر شعور شعور نہیں ہے۔ لفظ لفظ نہیں ہے۔ معنی معنی نہیں ہے۔ آپ آپ نہیں رہتے۔ ہم ہم نہیں بچتے۔ انکو درست مانے بغیر درست اور غلط کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ نفی اور اثبات کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وحدت اور کثرت بے معنی ہیں۔ اوپر اور نیچے بے معنی ہیں۔ پہلے اور بعد کے کوئی معنی نہیں۔ لفظ کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ معنی کے کوئی معنی نہیں ہیں۔
تو پھر اب کیا کریں؟
عرض یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو تسلیم کریں کہ اصول کی بنیاد تلاش کرنے کے عمل کا تسلسل لامتناہی نہیں ہے۔
پچھلی قسط میں وجودی لایعنیت کی پیدائش میں فلسفی کی اس بیزاری کا دخل بتایا گیا تھا کہ جو اصولوں کی لامتناہی پسپائی کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ کہ ہر اصول کے پیچھے ایک اصول ہے اور اسکے پیچھے ایک اور اصول، اور اصولوں کا یہ سلسلہ کہیں نہیں رکتا۔ تو ایسا نہیں ہے۔
فہم اور عقل کے اور حسیات کے بھی، وہ قبل تجربی اصول جن کی بنیاد پر پہلے درجے میں ہم شے کیساتھ نسبت پیدا کرتے ہیں جیسے زمان و مکان اور علت و معلول وغیرہ، (کچھ کے نزدیک یہ بارہ قواعد ہیں) وہ آخری ہیں۔ ادھر پہنچ کر سوال کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ کیونکہ سوال کا تصور خود بھی انکو درست مانے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ آ نہیں سکتا۔
اور خود ہی سوچیے، کیا “سلسلے” اور “تسلسل” کا تصور “زمان” کے بغیر ممکن ہے؟ ان قبل تجربی اصولوں کی آگے کوئی اور بنیاد نہیں ہیں۔ یہ اٹل اور حتمی ہیں۔ انکی بنیاد اگر ہے بھی تو آپ انکو درست مان کر ہی انکی بنیاد کھوج سکتے ہیں۔ مطلب اگر مکان کے پھیلاؤ کا انکار کرینگے، تو آپ بنیاد کہاں ڈھونڈنے جائینگے؟ اور اگر زمان سے فرصت غائب ہوجائے تو آپ کس وقت وہ بنیاد تلاش کرینگے؟ جب وقت ختم اور مکان گم ہوجائے گا تو ہر شے بنیاد سمیت غائب ہوجائے گی، نہ آپ بتاسکینگے کہ کہاں غائب ہوئی اور نہ آپکے پاس بتانے کیلئے وقت ہوگا۔
یہاں پہنچنے تک آپ نے مرحلہ وار دیکھ لیا کہ شعور اپنی پہلی جست ہی یقین کی لگاتا ہے۔ شعور کی آنکھ کھلنے کا عمل ہی اِن بنیادی اصولوں یعنی زمان/ مکان اور علت و معلول وغیرہ کو بغیر ثبوت کے درست مان لینے کا عمل ہے۔ کیونکہ ثبوت کا تصور بھی ان اصولوں کو مانے بغیر ممکن نہیں۔
اسلئے عقل ــ جو ہر وقت ثبوت! ثبوت! چیختی رہتی ہے اور اپنے پیرویان کو بھی ثبوت کے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہ کرنے کی نصیحت کرتے نہیں تھکتی اپنی پہلے حرکت ایک یقین کی بنیاد پر کرتی ہے۔ اس کا وجود ہی یقین پر کھڑا ہے۔ اس کا پورا بنیادی نظام، قواعد کے ایک ایسے مجموعے کو بغیر ثبوت کے مان لینے پر استوار ہے جس کیلئے اسکو کوئی دلیل مہیا ہو نہیں سکتی۔ ان قواعد کو مانے بغیر یہ ہل نہیں سکتی، سانس نہیں لے سکتی۔ یہاں تک کے یقین کے خلاف بول بھی نہیں سکتی۔
مصنف کی نظر میں یہ اٹل حقیقت ہی یقین کی وہ فلسفیانہ بنیاد ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔
اس بحث کا تتمّہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا انشا اللہ۔
تحریر کے اس آخری حصے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ یقین کو عقل کی اصل بنیاد ثابت کرنے کا اور سوالات کے لامتناہی تسلسل سے جنم لینے والی فلسفیانہ لایعنیت کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔
سوالات کے نہ ختم ہونے والے چکر سے جنم لینے والی بیزاری جو وجودی لایعنیت بن جاتی ہے، کے آگے اس بات کو ثابت کرنے سے کیا حاصل ہوگا کہ سوالات کا یہ معروف تسلسل لامتناہی نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ (قبل تجربی اصولوں کی حتمی حیثیت) پر رک جاتا ہے، جہاں پر اس میں “یقین” کا عنصر شامل کرنا ناگذیر ہوجاتا ہے۔
اس فلسفیانہ ذہن کو یہ باور کروانے سے کیا ملے گا کہ عقل کی پہلی حرکت ان قبل تجربی اصولوں پر غیر مشروط اور مکمل یقین کرنا ہے۔ اس یقین کے بغیر عقل بالکل بے کار بلکہ نابود ہے۔ یہ بات لایعنیت کے شکار ذہن پر ثابت کرنے سے ہم کن نتائج کی امید کررہے ہیں؟
یہ بات مصنف واضح کرچکا ہے کہ سوالات کے معروف تسلسل کا جس جگہ خاتمہ ہوتا ہے وہ قبل تجربی اصول ہیں، جن پر غیر مشروط یقین عقل کیلئے ناگذیر ہے اور عقل اپنا کوئی کام اس یقین کے بغیر نہیں کرسکتی۔
اس نتیجے پر پہنچنے والا آدمی اپنی عقل کو، جو اسے یہی سکھاتی رہتی ہے کہ ابھی ثبوت کافی نہیں اور ابھی دلیل کمزور ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم مجھے تو ثبوت پر چلنے کی نصیحتیں کرتی ہو اور خود قبل تجربی اصولوں پر بغیر ثبوت کے یقین کئے بیٹھی ہو!
تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ یقین ہی اصل ہے؟ جبکہ تمھارا اپنا حال یہ ہے کہ یقین کئے بغیر تمہارا وجود ہی معدوم ہے۔ تم مجھے یقین کا سہارا رکھتے ہوئے یقین کی کھوج کی طرف کیوں نہیں لگاتی جبکہ تمھارا اپنا طریقہ کار یہی ہے۔
یقین کے حق میں اس عقلی ثبوت کے فراہم ہوجانے سے آدمی کی فلسفیانہ اداسی اور وجودی لایعنیت کو ختم نہیں ہوجانا چاہئے؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ متبادل راستہ کیا ہے۔
ہمارے اردگرد زندگی کی تمام تر رنگینی اور کھلکھلاہٹ جس اصول پر کھڑی ہے وہ غفلت ہے۔ اصل اور سنگین حقیقتوں سے ہنس کر توجہ ہٹالینا۔ اصولوں کے بودے پن اور عارضی پن کو جب تک ممکن ہو اور جہاں تک ممکن ہو بھلائے رکھنا۔ سوال زیادہ تنگ کرنا شروع کردیں، تو اچھل کود شروع کردینا۔ بھاگ کھڑے ہونا۔ انتہائی حالتوں میں نشہ شروع کردینا۔ یہ سب اضطراری حرکتیں غفلت کے اُس پردے کو دبیز تر کرنے کی کوششیں ہیں جو انسان اور حقیقی سوالوں کے درمیان حائل رہتا ہے۔ جدید دنیا ان کوششوں کو انٹرٹینمنٹ کا خوشنما نام دیکر، اسکی اپنی مکروہ حقیقت پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔
اور ہاؤ و ہو کی دنیا چلتی رہتی ہے۔
جان لینا چاہئے کہ ایسی “انٹرٹینمنٹ” کے بعد جو مصنوعی اور عارضی توانائی محسوس کی جاتی ہے وہ غفلت کی توانائی ہے۔ کچھ مزید دیر کیلئے آپ اور میں زندگی کی اصل پر نظر کرنے کی اہلیت کھو چکتے ہیں۔ اور بدنصیبی دیکھیے کہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔
آج یہ فلم، کل وہ ڈرامہ، پرسوں ادھر شاپنگ، پھر ادھر آؤٹنگ۔ فلاں ریستوراں میں ڈائن آؤٹ۔
یہ جوتا، وہ پتلون، فلاں رنگ، یہ بیگ، وہ سوٹ۔
اور جب یہ سب کرچکیں اور کھا چکیں اور پہن چکیں، تو پیش قدمی کرتی ہوئی بوریت کے خوف سے کسی مزید “انٹرٹینمنٹ” کی تلاش۔
ایک طریقہ تو اداسی اور لایعنیت دور کرنے کا یہ ہے، جو عام لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ یہ نسبتاً آسان راستہ ہے، بہت چلا ہوا ہے اور عام دستیاب بھی ہے۔ عارضی ہے مگر زود اثر ہے۔ ایک پوری مشینری اس راستے پر گھات لگائے منتظر رہتی ہے کہ کب کوئی خوفزدہ مفرور فلسفی بھی اس راستے پر آئے اور ہم اسکی نظر کو چمک دمک دکھا کر اچک لیں۔ لوگ جوق در جوق اس رستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نئی دکان سجی ہوئی ہے۔ خوشنما، رنگ برنگی اور نہ ختم ہونے والی اشیاء کا ایک انبار ہے جو بلّوریں الماریوں کے اندر سے غفلت کی سر عام دعوت دیتی ہیں۔ اور لوگ نگل لئے جاتے ہیں۔ خوف زدہ لوگ جو سوالوں سے ڈرتے ہیں ان الماریوں میں قید ہوجاتے ہیں۔ اشیاء کی چمک دمک انکو اسیر کرلیتی ہے۔ جب ایک شے پرانی ہوجائے تو ایک نئی شے اس خوفزدہ آدمی کو اپنے دام میں پھانس لیتی ہے۔
غفلت کی اس بھول بھلیوں میں سرگرداں ہر شخص زیادہ کی طلب میں ہے۔ ہر شخص کیلئے اسکی حصول کردہ شے اب وجہ اطمینان نہیں رہی۔ ایک انبوہ ہے جو “ھل من مزید” پکارتا بھاگتا چلا جاتا ہے۔ نشے کی ختم نہ ہونے والی ایک طلب ہے کہ جس میں ہر دفعہ سرور حاصل کرنے کیلئے نشے کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ پاتال میں اترتی ہوئی ایک منحوس سیڑھی جسکے ہر زینے پر ایک نئے طرز کا خوشنما پھندا لٹک رہا ہے۔
دوسرا راستہ یہ ہے کہ سوالوں کا سامنا کیا جائے۔ یہ مستند فلسفیانہ رستہ ہے۔ عقلی راستہ ہے۔ اس رستے پر چلنے والے لوگ مگر کم ہیں۔ فلسفی کم ہی ہوتے ہیں۔ آپ اسی حقیقت کو دیکھ لیں کہ ایک فلسفیانہ تحریر پڑھنے والوں کی تعداد ایک چٹخارے والی کہانی پڑھنے والوں کی تعداد کے مقابلے میں کتنی کم ہوتی ہے۔
موضوع پر واپس آکر بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔
اس بات کے ثبوت مہیا ہوجانے کے ساتھ، کہ عقل اپنی بنیاد قواعد کے ایک مجموعے پر یقین کے بعد استوار کرتی ہے، یہ بات غیر عقلی ہے کہ یقین سے صرف نظر کیا جائے۔ یقین کو بلائینڈ فیتھ کہہ کر اسکے خلاف ایک تحقیری رویہ اپنایا جائے۔ یہ رویہ فلاسفہ کی اکثریت کے ہاں موجود ہے تاہم یہ دکھایا جا چکا ہے کہ اس رویے کی کوئی عقلی بنیاد کم ازکم نہیں ہے۔
عقل ہی ہمیں عقل کی مجبوریوں سے آگاہ کرتی ہے۔ عقل ہی عقل کیلئے یقین کی ناگزیریت کو ہماری عقل پر آشکار کرتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فلسفی یقین کو کمتر سمجھتے ہیں۔؟
مذھبی نظام کے اندر یقین کی مرکزیت جسکو مذھب ایمان کے نام سے بیان کرتا ہے فلسفہ کے بالکل متضاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ فلسفہ جو عقلیات کی بیساکھی کیساتھ چلتا ہے، کے پاس یقین کو کمتر سمجھنے کا کوئی عقلی جواز نہیں ہے۔
جس عقلیات کے سہارے وہ چل رہا ہے، وہ عقلیات خود یقین کے سہارے چل رہی ہے۔
یہاں پہنچ کر اس سوال کا جواب اب براہ راست دیا جاسکتا ہے کہ کیا یقین کی ناگزیریت عقل پر ثابت ہوجانے کے بعد فلسفی کو اپنی لایعنیت اور لغویت سے آزاد ہوجانا چاہئے؟
فلسفیانہ لغویت اور لایعنیت کا حل غفلت کے عارضی طریقے سے کرنا تو مزید مایوسی پیدا کرتا ہے۔ فلسفی کو لایعنیت سے نمٹنے کیلئے بامعنی سوال درکار ہیں تاکہ وہ اپنی توانائیاں ان سوالوں کے جواب کھوجنے میں صرف کردے۔
یقین ایک ایسا ہی بامعنی سوال ہے۔ یقین جواب بھی ہے مگر اس بات کے سامنے آنے پر کہ عقل اپنی بنیاد یقین پر استوار کرتا ہے، فلسفی کو خود یقین کی ماہیت پر غور کرنے کے راستے پر چل پڑنا چاہئے، اس علم کیساتھ کہ یہ غور وفکر بھی یقین کے اصول پر استوار عقل ہی کی بنیاد پر ممکن ہے۔
یقین کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ یقین میں پختگی اور مظبوطی پیدا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ جو طریقے بیان کئے جاتے ہیں انکی فلسفیانہ حیثیت کیا ہے؟ وغیرہ
یہاں سے آگے سوالات کو ایک اور مختلف رخ اختیار کرنا چاہئے جس کے اندر یقین ایک اہم اور بنیادی جزو کے طور پر شامل حال رہے۔
اور اگر عقل بطور ذریعہ علم، یقین پر مبنی ہونے کی بنیاد پر قابل اعتبار نہیں، تو آدمی کے پاس علم کے حصول کا کیا کوئی اور ذریعہ بھی ہے؟
وجودی لایعنیت بے معنی سوالات کی بے بنیاد تکرار سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حل جبکہ غفلت میں تلاش کرنا اس کیفیت کی شدت میں بالآخر مزید اضافہ کرتا ہے، یقین کو ساتھ رکھ کر کئے گئے بامعنی سوالات کی دریافت اور جوابات کی کھوج فلسفی کو پھر سے اسکی کھوئی ہوئی معنویت عطا کرسکتے ہیں۔
تاریخی طور پر سوالات کی معروف بے بنیاد تکرار موجودیت پسند فلاسفہ تک پہنچتے پہنچتے اس قدر لغو ہوگئی تھی کہ انکے اندر حیات دشمن اور حیات کُش رویے جنم لینے لگے اور کچھ نے تو خودکشی کرنے کو حل کے طور پر بھی پیش کیا۔
ہمارے ملک کے اکثر نوجوان فلسفیانہ اذہان اس غیر عقلی رویے کو فلسفیانہ رویہ سمجھتی ہے اور ایک زاویے سے اس سے رومان کشید کرتی اور اس پر فخر بھی کرتی ہے۔
ہماری نظر میں یہ نیم فلسفیانہ رویہ غیر معیاری، بے راہ اور نامکمل تفلسف سے پیدا ہوا ہے اور اس قید سے اصولِ یقین پر استوار بامعنی سوالات کے سہارے نکلا جا سکتا ہے۔
تحریر ڈاکٹر خالد ولی اللہ بلغاری